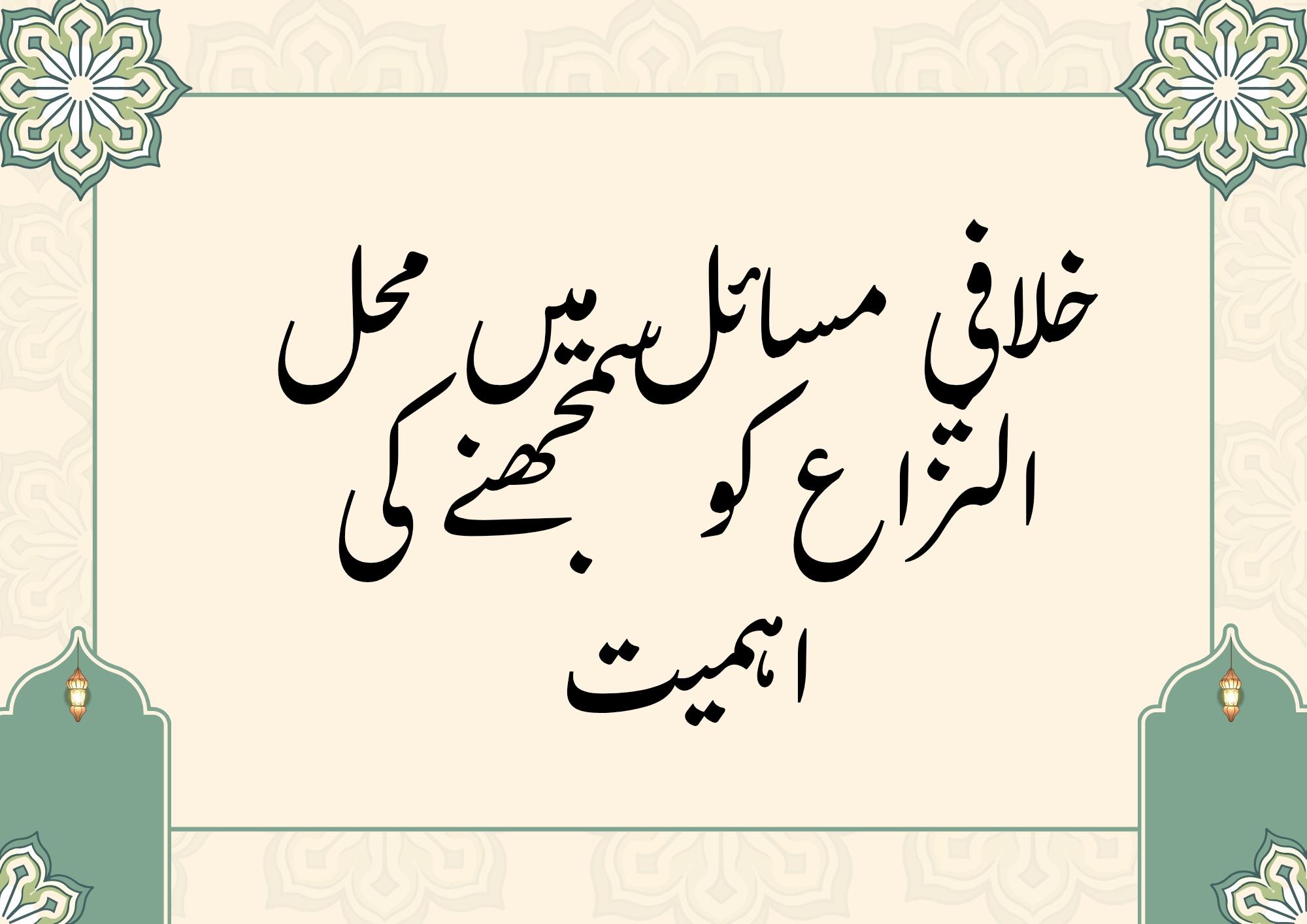
خلافي مسائل میں محل النزاع کو سمجھنے کی اہمیت
عامر نذیر
(زیرِ تعلیم جامعہ عبد العزیز جِدّہ)
علومِ اسلامیہ، خصوصاً علومِ آلات کی تاریخ پر اگر دورِ نشاۃ سے لے کر عصرِ استقرار تک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بے شمار ایسے مسائل پیدا ہوئے جن میں اہلِ علم کے مابین وسیع علمی اختلافات رونما ہوئے۔ ان مسائل پر بحث کے دوران علماء نے اپنے نظریات کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت اور علومِ عقلیہ سے استدلالات و استنباطات پیش کیے، اور مخالفین کے افکار کو رد کرنے کے لیے مضبوط دلائل اور منطقی منہج اختیار کیا۔ ان مباحث کا جب بغور مطالعہ کیا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ہمارے اکابرین نے کس قدر عمیق فکری استعداد اور استدلالی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔
ان علمی اختلافات کے نتیجے میں مناظرات اور مباحثوں کو اتنی اہمیت دی گئی کہ یہ مستقل فن کی حیثیت اختیار کر گئے، جسے بعد میں "علم الجدل" کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس فن کی ضرورت، اہمیت، اور اس کے بنیادی اصول و مباحث پر بے شمار تصانیف لکھی گئیں، جن میں جمال الدین عثمان بن الحاجب المالکی (متوفی 646ھ) کی "منتہی الوصول والأمل فی علمی الأصول والجدل" سرِفہرست ہے۔ بعد ازاں، اسی کتاب کا ایک مختصر نسخہ "مختصر منتہی السؤل والأمل فی علمی الأصول والجدل" کے نام سے مرتب کیا گیا، جو "مختصر ابن الحاجب" کے نام سے مشہور ہے اور بعد میں آنے والے علمائے اصول کے لیے ایک بنیادی ماخذ بنی۔
یہی وجہ ہے کہ اصولِ فقہ کے بڑے بڑے علماء نے اس کتاب پر بھرپور توجہ دی اور اس کے دقیق مباحث کو واضح کرنے اور مشکل نکات کو کھولنے کے لیے متعدد شروحات لکھیں۔ ان میں نمایاں شخصیات میں عضد الدین ایجی، ابن السبکی، شیرازی، بیضاوی شافعی، ضیاء الدین طوسی، بدر الدین تستری، اور شمس الدین اصفہانی شامل ہیں۔
یہ کتاب علم الجدل کے منہج پر ترتیب دی گئی ہے، جو منطقی مباحث، مقدمات، اور مبادئ اللغات پر مشتمل ہے۔ شاید ہی اس میں کوئی ایسا مسئلہ مذکور ہو جس میں مخالفین کے ساتھ علمی جدل اور بحث و تمحیص نہ کی گئی ہو۔
محل النزاع تک رسائی کی ضرورت
اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ علمی اختلافات (مسائلِ خلافیہ) کو سمجھنا ہر طالب علم اور محقق کے لیے یکساں آسان نہیں، کیونکہ انسانی فہم میں تفاوت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ البتہ، اگر کوئی شخص صحیح منہج اور علمی اصولوں کے مطابق ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس تفاوت کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔
اکثر اوقات طلبہ اور بعض اوقات علماء بھی علمی اختلافات کا محض سطحی مطالعہ کرتے ہیں اور اسے ہی مکمل علم سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ مثبتین اور مخالفین کے اقوال کا احاطہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، تو وہ شاید ہی اس کی حقیقی نوعیت بیان کر سکیں۔ اس کی مثال "أحير من الذئب في أرض اليهماء" (یعنی صحرائی زمین میں بھیڑیا حیران) یا "لا ناقة لي فيها ولا جمل" (یعنی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں) کی سی ہوگی۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ مسئلے کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں مگر اس کے اصل منبع یعنی محل النزاع (نقطۂ اختلاف) تک نہیں پہنچ پاتے۔
کسی بھی خلافی مسئلے کی حقیقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے محل النزاع کا ادراک ضروری ہوتا ہے۔ جب کسی طالب علم یا عالم کو اس حقیقت کا شعور حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس سے متعلق دیگر علمی مباحث، اعتراضات، مناظرات، اور مناقشات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے یہ مسئلہ عقدی (عقیدے سے متعلق ہو)، اصولی (اصولِ فقہ سے متعلق ہو)، یا فقہی (فقہ سے متعلق ہو)، اس کا صحیح فہم ممکن ہو جاتا ہے۔
مثالیں برائے وضاحت
(1) مسئلۂ تأثیر الاسباب فی المسببات (اسباب کا مسببات پر اثر انداز ہونا)
یہ ایک عقدی مسئلہ ہے، جس میں اشاعرہ کا مؤقف یہ ہے کہ اسباب بذاتِ خود کسی اثر کے حامل نہیں، بلکہ ہر شے کا مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ مثال کے طور پر:
آگ سے کپڑا جلتا ہے
پانی سے پیاس بجھتی ہے
کھانے سے بھوک مٹتی ہے
لیکن اشاعرہ ان تمام اشیاء میں سببیت (Cause-and-Effect Relationship) کے قائل نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب محض عادت اللہ ہے، اور حقیقی مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
امام ابو الحسن اشعریؒ فرماتے ہیں:
"اذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري تعالى لا يشاركه في الخلق غيره، فأخص وصفه تعالى هو القدرة على الاختراع"
(الملل والنحل 1/110)
یعنی "جب حقیقی خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس صفت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور تخلیق کی قدرت اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں سے ہے۔"
اسی طرح، امام غزالیؒ کہتے ہیں:
"ومذهب اهل الحق ان المؤثر هو قدرة الله تعالى وان الأسباب لا اثر لها"
(مجموع الرسائل للغزالی)
یعنی "اہلِ حق کا مذہب یہ ہے کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اسباب کا کوئی حقیقی اثر نہیں۔"
جبکہ فلاسفہ کے نزدیک اسباب بذاتِ خود مؤثر ہیں، جو اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ کائنات میں متعدد فاعلین (Multiple Creators) ہوں، جو کہ توحید کے خلاف ہے۔
(2) مسئلۂ تحسین و تقبیح عقلی
یہ مسئلہ اصولِ فقہ میں بھی زیرِ بحث آتا ہے، جس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ:
کیا عقل کسی شے کے حسن و قبح کو مستقل طور پر جان سکتی ہے؟
کیا احکامِ شرعیہ کی بنیاد عقل کے ادراک پر رکھی جا سکتی ہے؟
کیا عقل، اوامر و نواہی کے تعین میں خودمختار ہے؟
یہاں بھی اصل محل النزاع کو سمجھے بغیر اس مسئلے کا درست فہم حاصل نہیں ہو سکتا۔
(3) نماز کے دوران پانی دستیاب ہو جائے تو کیا تیمم کرنے والا نماز مکمل کرے یا دہرائے؟
یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، جس میں شافعیہ کے نزدیک وہ نماز مکمل کرے گا، جبکہ حنابلہ وغیرہ کے نزدیک اسے اعادہ کرنا ہوگا، کیونکہ تیمم پانی نہ ہونے کی بنا پر جائز تھا، اور جب پانی مل گیا تو اس کا جواز ختم ہو گیا۔
یہاں بھی اصل اختلاف اس اصول پر ہے کہ:
"محل الخلاف میں استصحاب الاجماع السابق جائز ہے یا نہیں؟"
(تخريج الفروع على الأصول للزنجانی، ص ٧٣)
اگر اس تحریر کے مفہوم کو چند الفاظ میں بیان کیا جائے تو اسے یوں خلاصہ کیا جا سکتا ہے: ہر علمی بحث میں محل النزاع تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے۔ جب یہ واضح ہو جاتا ہے، تو اختلافات کی نوعیت، اسباب، اور ان کے علمی و منطقی دلائل بہتر انداز میں سمجھے جا سکتے ہیں، اور یوں علمی اختلافات کی روشنی میں گہرائی سے مطالعہ ممکن ہو جاتا ہے۔
